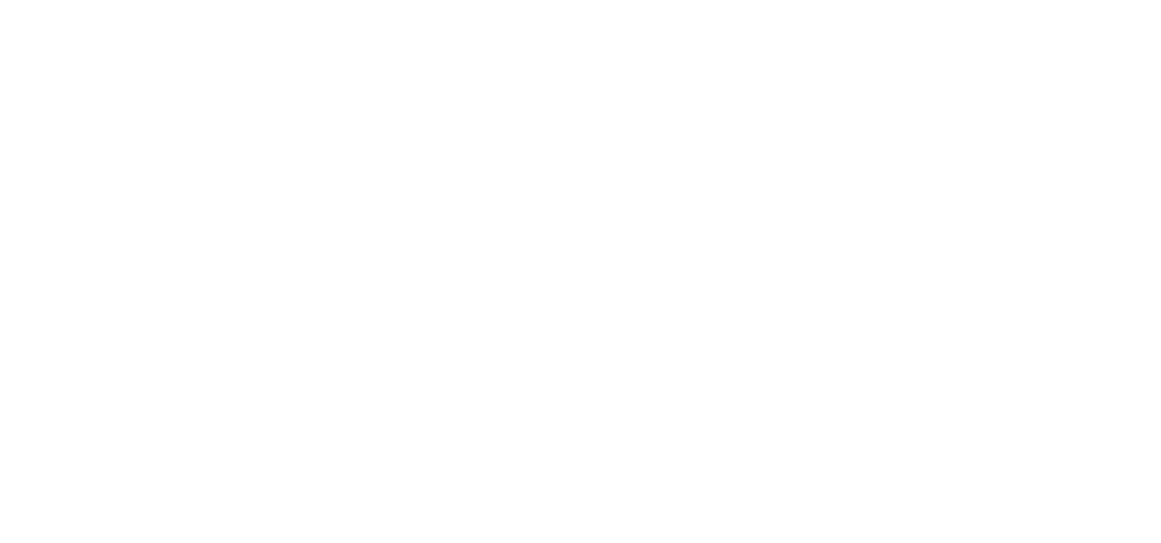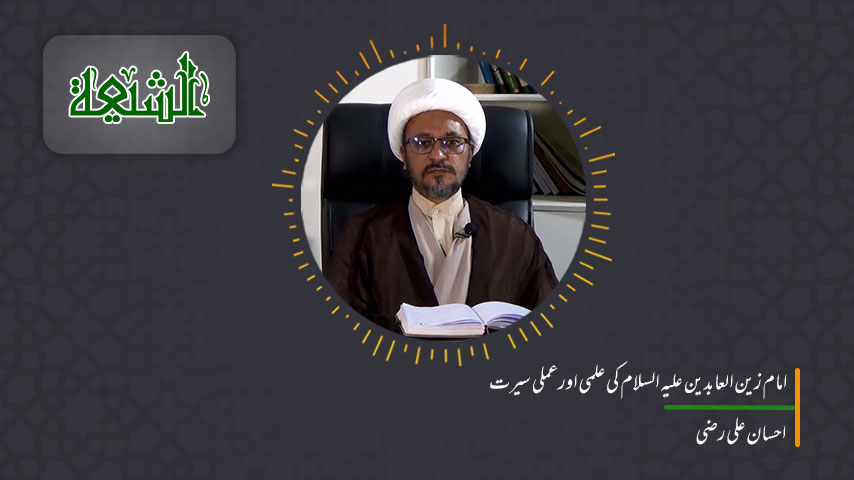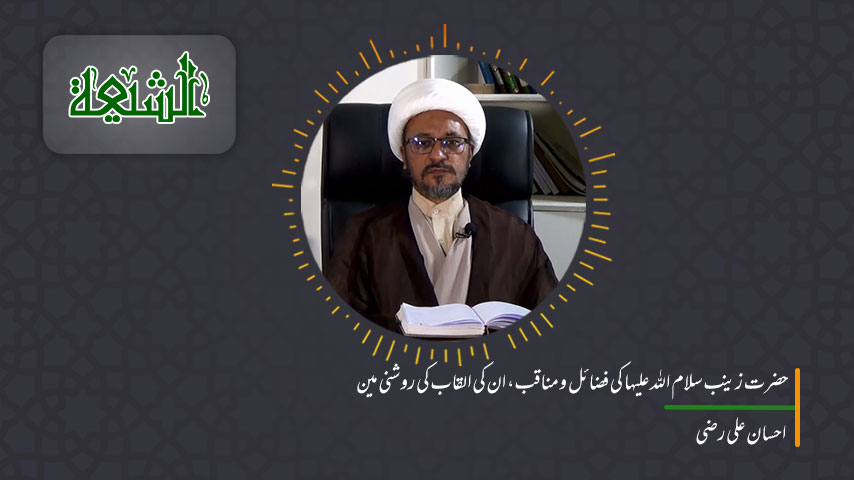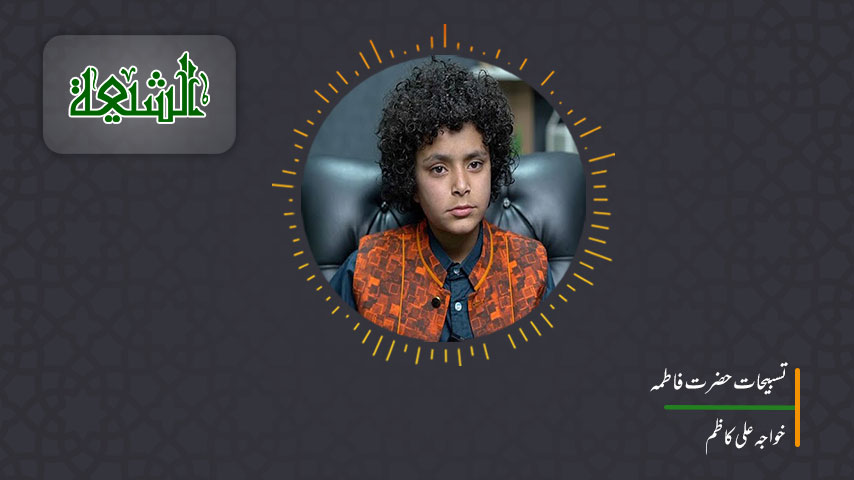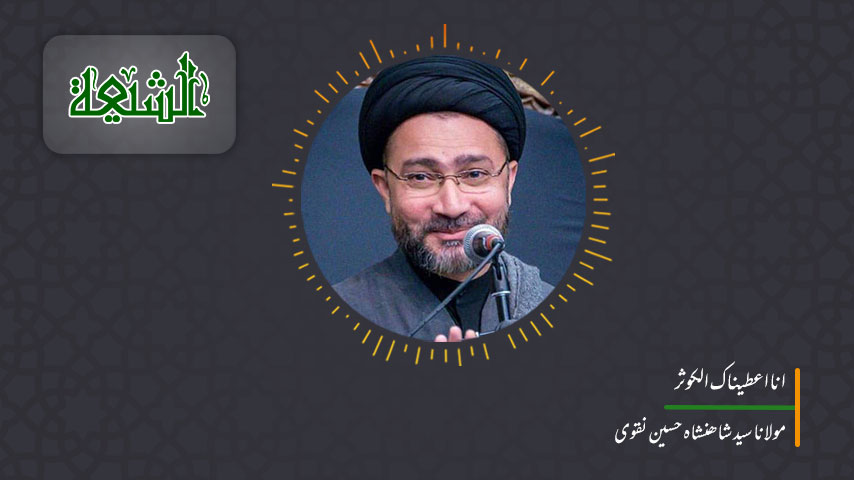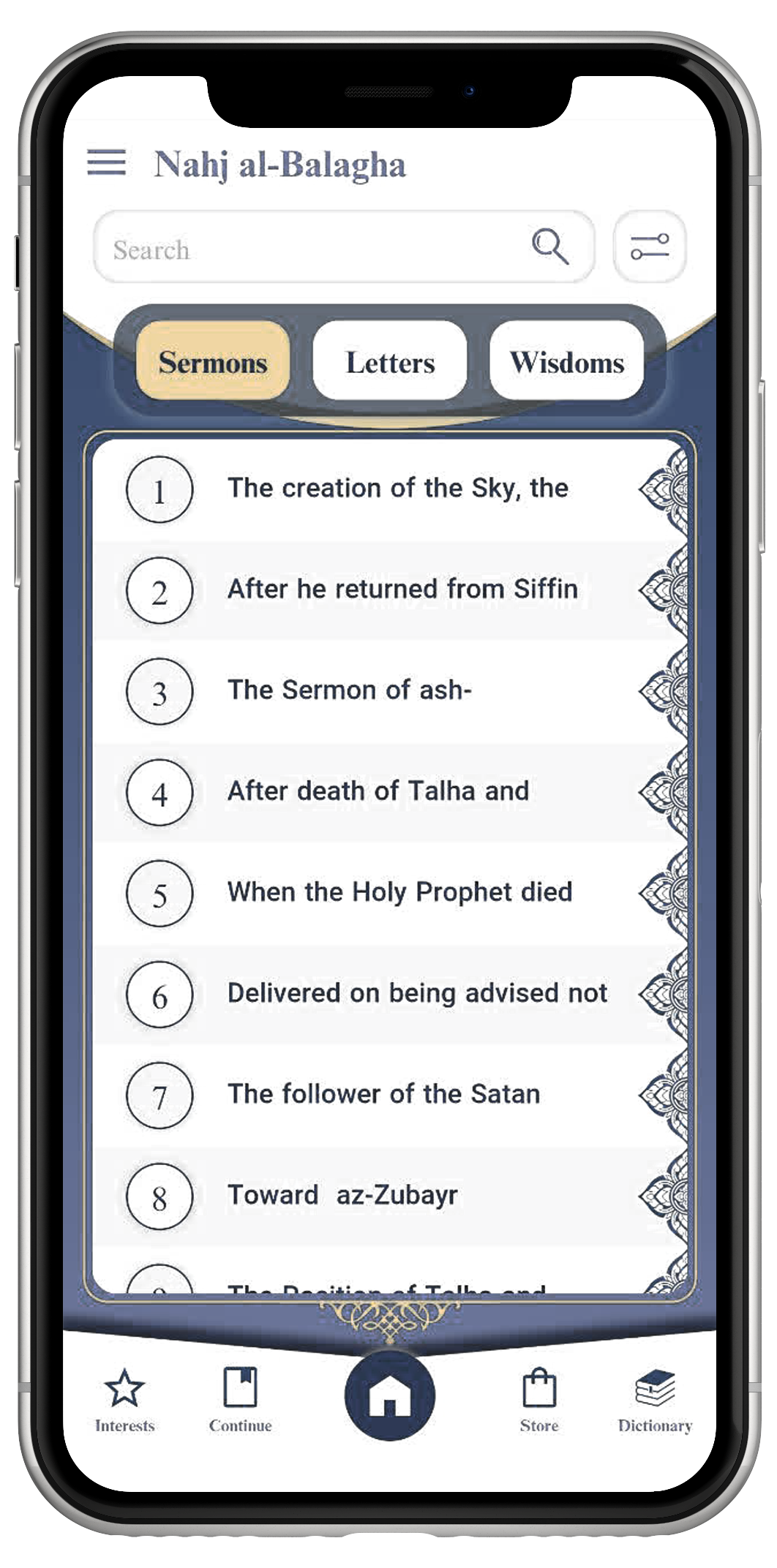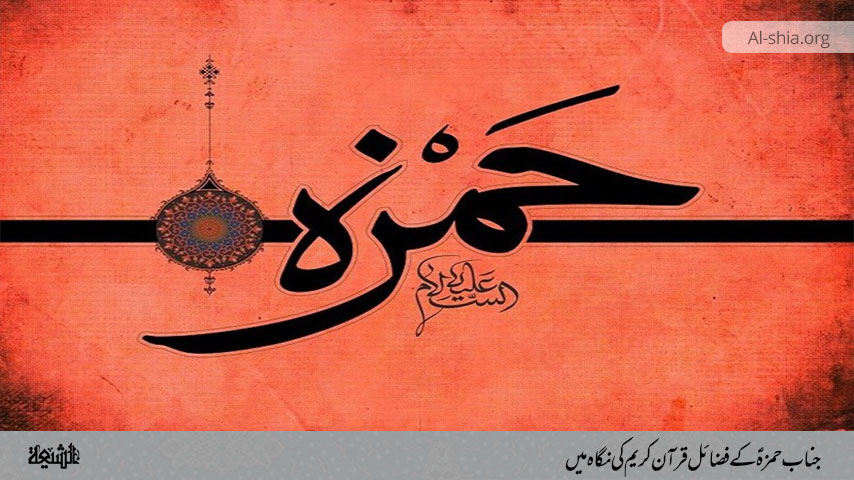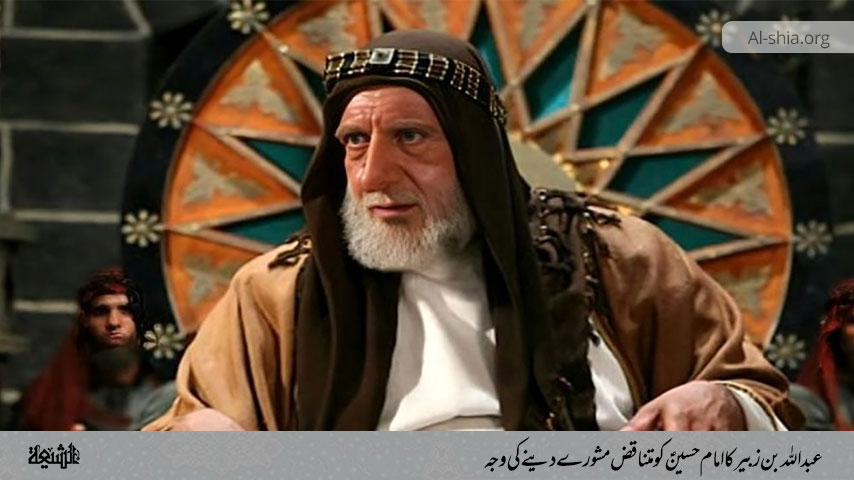انسان کی انسانیت اور حیوانیت کے باہم رابطہ یا دوسرے الفاظ میں انسان کی ثقافتی تمدنی اور معنوی زندگی کے ساتھ اس کی مادی زندگی کے رابطے سے علم و ایمان کا رخ روشن ہوگا۔ جس سے علم و ایمان کے بارے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی انسانیت، اصالت و استقلال رکھتی ہے یہ فقط اس کی حیوانی زندگی کا پر تو نہیں ہے۔ علم و ایمان انسان کی انسانیت کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو ارکان یا دو رخوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے یا آئندہ کیا رابطہ ہو سکتا ہے؟
علم و ایمان؛ ابتدائی اشارہ
واضح ہے کہ علم و ایمان، انسان کی انسانیت کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو ارکان یا انسانیت کے ان دو رخوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے یا آئندہ کیا رابطہ ہو سکتا ہے؟
علم و ایمان کے بارے میں یہ بات قابل افسوس ہے کہ عیسائیوں کے ہاں عہد عتیق (تورات) کے بعض تحریفی حصوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک فکر راسخ ہو چکی ہے جو علم و ایمان دونوں کو مہنگی پڑی ہے اور وہ فکر یہ ہے کہ علم و ایمان باہم متضاد ہیں۔ اس فکر کی اصل بنیاد وہی سوچ ہے۔ جو "عہد عتیق” کے "سفر پیدائش” میں ملتی ہے۔
جو شناخت سفر پیدائش میں بیاں کی گئی ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ خدا (دین) کا حکم یہ ہے کہ انسان نیک و بد کی پہچان حاصل نہ کرے آگاہی و معرفت کے قریب نہ پھٹکے۔ آگاہی کو شجرہ ممنوعہ قرار دیا گیا ہے۔ انسان گناہ کا ارتکاب اور خدا کے حکم سے روگردانی کر کے (شریعت اور پیامبروں کی تعلیمات سے منہ موڑ کر) معرفت و آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔
اسی بناء پر اسے بہشت سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق تمام وسوسوں کا سرچشمہ آگاہی ہے لہذا وسوسے کرنے والا شیطان در حقیقت عقل ہی ہے۔ یوں علم و ایمان میں سے ایک دوسرے پر ترجیح دینا ہوگی۔
علم و ایمان کا باہمی رابطہ؛ تفصیلی وضاحت
علم و ایمان کے باہمی رابطے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ خدا نے حضرت آدم (ع) کو تمام اسماء (حقائق) بتا دئیے اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ شیطان اس لئے راندہ درگاہ ہوا کہ اس نے حقائق سے آگاہ خلیفة اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اسی طرح سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شجرہ ممنوعہ حرص و طمع جیسی تھیں یعنی ایسی جو آدم کی حیوانیت سے متعلق تھیں یہ چیزیں اس کی انسانیت سے مربوط نہ تھیں۔
شیطانی وسوسے ہمیشہ عقل کے خلاف اور حیوانی ہوائے نفس کے ہوتے ہے۔ انسانی وجود میں مظہر شیطان، عقل نہیں نفس امارہ ہے۔ بنابرایں قرآن و سنت کی ان تعلیمات کے پیش نظر "سفر پیدائش” کے مطالب ہمارے لئے انتہائی تعجب خیز ہیں۔
اسی فکر نے یورپی تمدن کی تاریخ کو گذشتہ پندرہ صدیوں میں ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ایک دور کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسرے دور کو علم کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس فکر نے علم و ایمان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا ہے۔
اسلامی تمدن کی تاریخ ان ادوار میں تقسیم ہوتی ہے؛ ایک عروج کا زمانہ جو علم و ایمان کا زمانہ ہے۔ دوسرا زوال کا زمانہ کہ جس میں علم و ایمان دونوں انحطاط و پستی کا شکار ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ان کی اس غلط فکر سے دور رہنا چاہئے جس کی وجہ سے علم و ایمان اور انسانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے خواہ مخواہ علم و ایمان کو باہم متضاد نہیں سمجھنا چاہئے۔
ہر ایمان کی بنیاد بہر حال کائنات کے بارے میں ایک خاص فکر و نظر پر قائم ہوتی ہے اور بلا شبہ کائنات کے بارے میں ایسے متعدد افکار و عقائد علمی اصولوں کے مطابق نہیں ہیں اور جو بہرحال مسترد کردئیے جانے کے قابل ہیں۔
آیا کائنات و ہستی کے بارے میں کوئی ایسی فکر یا نظریہ موجود ہے جو سائنس و فلسفہ اور منطق کی کسوٹی پر بھی پورا اترتا ہو اور سعادت بخش ایمان کے لئے ایک مضبوط بنیاد بھی بن سکے؟ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایسی فکر یا تصور کائنات میں موجود ہے تو پھر انسان مجبور نہیں کہ دو بد بختیوں میں سے کوئی ایک ضرور اس کے نصیب میں ہو بلکہ علم و ایمان کے بحث کا راستہ روشن ہو جائے گا۔
علم و ایمان؛ دو اوزار
علم اور ایمان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ علم روشنی اور توانائی عطا کرتا ہے، جبکہ ایمان عشق، امید اور دل کی گرمی کا باعث بنتا ہے۔ علم آلات اور وسائل تخلیق کرتا ہے، جبکہ ایمان مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ علم رفتار میں تیزی لاتا ہے، جبکہ ایمان علم کی سمت متعین کرتا ہے اور اچھائی کی خواہش رکھتا ہے۔ علم یہ بتاتا ہے کہ کیا ہے، جبکہ ایمان ہدایت کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہئے۔
علم و ایمان کو اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ علم، بیرونی انقلاب ہے اور ایمان، اندرونی انقلاب ہے۔ علم جہان کو جہان آدمیت بناتا ہے اور ایمان، روح کو روح آدمیت بناتا ہے۔ علم، انسانی وجود کو افقی سطح تک ترقی دیتا ہے اور ایمان، انسان کو عمودی سطح پر اوپر لے جاتا ہے۔ علم، طبیعت ساز ہے اور ایمان، انسان ساز۔ علم بھی انسان کو طاقت عطا کرتا ہے اور ایمان بھی لیکن علم کی طاقت منفصل ہوتی ہے اور ایمان کی طاقت متصل ہوتی ہے۔
علم و ایمان کے بارے میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم، جمال ہے اور ایمان بھی جمال لیکن علم، حسن عقل اور ایمان، جمال روح۔ علم حسن فکر ہے اور ایمان، جمال احساس۔ علم بھی انسان کو اطمینان عطا کرتا ہے اور ایمان بھی۔ علم، اطمینان خارجی عطا کرتا ہے اور ایمان، سکون داخلی۔ علم، بیماری، سیلاب، زلزلہ اور طوفان کے مقابل پناہ گاہ ہے اور ایمان، اضطراب، پریشانی، تنہائی، احساس محرومی اور بے وقتی کے مقابل پناہ گاہ ہے۔
علم و ایمان کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم، دنیا کو انسان کے لئے سازگار کرتا ہے اور ایمان انسان کو انسان کے لئے سازگار کرتا ہے۔ انسان کے لئے علم و ایمان کی اکٹھی ضرورت ہے۔ یہ بات مذہبی و غیر مذہبی مفکرین کی انتہائی توجہ کا مرکز رہی ہے۔
علم و ایمان کا ٹوٹنا؛ مغربی اخلاقی پستی
علامہ اقبال کہتے ہیں:
آج کا یورپ انسانی اخلاق کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے، جبکہ مسلمان وحی پر مبنی ایسے افکار اور نظریات سے مالا مال ہیں جو زندگی کی گہرائیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ افکار ان کے ظاہری وجود کو باطنی رنگ عطا کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے زندگی کا روحانی پہلو ایک اعتقادی مسئلہ ہے، اور اس اعتقاد کے دفاع میں وہ خوشی سے جان کی بازی لگا دیتا ہے۔[1]
ویل ڈیورانٹ، مشہور کتاب "تاریخ تمدن” کا مصنف، اگرچہ غیر مذہبی شخص تھا، اس کے باوجود کہتا ہے کہ قدیم دنیا اور آج کی جدید مشینی دنیا میں فرق صرف وسائل کی بنیاد پر ہے۔ مقاصد کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب اس مسئلے پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہماری تمام تر ترقی و پیش رفت صرف وسائل اور طریقوں کی اصلاح تک محدود ہو اور اہداف و مقاصد بہتر نہ ہوں؟[2]
مزید کہتا ہے کہ "دولت تھکا دیتی ہے عقل و حکمت ایک سرد اور دھیمی ہی روشنی ہے لیکن عشق ناقابل بیان حد تک دلجوئی کرتے ہوئے دلوں کو گرماتا ہے۔”[3]
اس خلأ کو محسوس کرنے والوں میں سے ایک ویل ڈیورنٹ بھی ہے اس نے ادب فلسفہ اور آرٹ کے ذریعے اس خلأ کو پر کرنے کی تجویز دی ہے۔[4]
یہ بات انتہائی تعجب انگیز ہے کہ ویل ڈیورنٹ اعتراف تو کرتا ہے کہ موجودہ بحران اعتقادی بحران ہے۔ یہ خلأ عقائد، اہداف اور مقاصد کا خلأ ہے۔ ایک ایسا خلأ جو بے ہودہ پستیوں کا شکار ہے۔
علاوہ ازیں ویل ڈیورنٹ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ خلأ انسانی اہداف اور مقاصد کے بارے میں کوئی خاص سوچ اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ان تمام اعترافات کے باوجود اس کا خیال یہ ہے کہ ہر طرح کی معنویت سے اس کی چارہ جوئی ہو سکتی ہے خواہ وہ معنویت قوت تخیل تک ہی محدود کیوں نہ ہو۔
علم و ایمان کی جانشینی
علم و ایمان متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ علم کا کیا کردار ہے اور ایمان کیا کردار ادا کرتا ہے تو ایسے سوال اور جواب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
یہ بات واضح ہے کہ علم، ایمان کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں کہ علم توانائی اور روشنی کے ساتھ ساتھ عشق و امید بھی عطا کرے اور علم ہماری خواہشات کی سطح بلند کرے اور اس کے علاوہ اہداف و مقاصد کے حصول میں مدد دے۔
علم و ایمان میں یہ نکتہ بھی ضروری ہے کہ علم کوئی ایسا آلہ نہیں جو ہماری ماہیت اور جوہر کو بدل سکے اسی طرح ایمان بھی علم کا جانشین نہیں ہو سکتا۔
ایمان ہمیں جہان طبیعت کی پہچان بھی نہیں کروا سکتا۔ اس پر حاکم قوانین پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ہمیں ہماری پہچان بھی نہیں کروا سکتا۔ تاریخی تجربات اس امر کی نشان دہی کرتے ہیں کہ علم و ایمان کی جدائی سے انسانی معاشرے نے ناقابل تلافی نقصانات اٹھائے ہیں۔ ایمان کی شناخت علم ہی کے سائے میں ہونی چاہئے۔ ایمان علم کی روشنی میں خرافات سے دور رہتا ہے۔
یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا علم نور اور طاقت نہیں ہے؟ علم کا نور اور طاقت ہونا فقط بیرونی دنیا سے متعلق نہیں ہے بلکہ علم ہمارے اندر کی دنیا بھی ہمیں دکھاتا ہے اور اسے ہم پر واضح کرتا ہے بنا برایں ہمیں اپنے اندر کی دنیا تبدیل کرنے کی طاقت بھی عطا کرتا ہے لہذا علم دنیا کی بھی تعمیر کر سکتا ہے اور ایمان کا کام (انسان سازی) بھی کرتا ہے!!
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ سب باتیں درست ہیں لیکن یہاں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ علم کی قدرت و توانائی ایک اوزار کی سی طاقت و توانائی ہے یعنی اس کا انحصار انسان کے ارادے اور حکم پر ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کوئی کام کرنا چاہے تو علم کے آلہ کی مدد سے بہتر انجام دے سکتا ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مقاصد کے حصول میں علم انسان کا بہترین مددگار ہے۔
انسان آلات کے استعمال سے پہلے مقصد پیش نظر رکھتا ہے کیوں کہ آلات ہمیشہ مقصد کے حصول کے لئے خدمت پر مأمور ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ مقاصد کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟
گذشتہ دو تین صدیوں کو سائنس پرستی اور ایمان سے فرار کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت سے دانشوروں کی یہ رائے بنی کہ انسان کی تمام تر مشکلات کا حل سائنس میں پوشیدہ ہے۔ لیکن تجربہ نے اس کے خلاف ثابت کیا اور آج دنیا میں کوئی دانشور ایسا نہیں جو انسان کے لئے ایمان کی کسی نہ کسی صورت کی ضرورت کا قائل نہ ہو اگرچہ یہ ایمان غیر مذہبی ہی کیوں نہ ہو۔ بہر حال ماورائے سائنس کسی اور چیز کی ضرورت پر اب سب متفق ہیں۔
برٹرینڈ رسل مادی رجحانات کے باوجود معترف ہے کہ "ایسا کام جس میں صرف آمدن پیش نظر ہو اس کا نتیجہ زیادہ ثمر آور نہیں ہوتا۔ ایسے نتیجہ کے لئے کام اختیار کرنا چاہئے جس میں کسی ہدف مقصد اور فرد پر ایمان بھی مضمر ہو۔”[5]
اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان نظری و فکری اعتبار سے مادی ہو اور عملاً معنوی (مثالی و آئیڈیلسٹ)۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ اور مشکل مسئلہ ہے جسے مادہ پرست ہی حل کر سکتے ہیں۔
جارج سارٹن دنیا کا مشہور و معروف دانشور اور مقبول ترین کتاب "تاریخ سائنس” کا مصنف ہے۔ انسان کو انسان بنانے اور انسانیت کی بنیادوں پر بشری تعلقات استوار کرنے میں علم کی نارسائی اور انسان کے لئے ایمان کی اشد و فوری ضرورت کو یوں بیان کرتا ہے:
جارج سارئن انسان کے لئے مذہبی و دینی ایمان کی ضرورت کا اعتراف کرتا ہے انسان کے لئے "آرٹ مذہب اور سائنس” کی مثلث کے ضروری ہونے پر گویا ہے کہ
"آرٹ حسن کو آشکار کرتا ہے اور یہی زندگی کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ دین محبت کا پیغمبر اور زندگی کی موسیقی ہے۔ سائنسی کا سروکار حق سچ اور عقل کے ساتھ ہے جو نوع بشر کی ہوشمندی کا باعث ہے ہمیں ان تینوں کی ضرورت ہے۔ آرٹ بھی ضروری ہے دین بھی چاہئے اور سائنس کی ضرورت لازمی ہے زندگی کے لئے مطلق صورت میں سائنس کی ضرورت لازمی ہے لیکن تنہا سائنس کسی صورت بھی کافی نہیں۔”[6]
علم و ایمان؛ مذہبی ایمان کے زاویے سے
علم و ایمان کی بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان عقیدہ و ایمان کے بغیر نہ صحیح زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی بشریت اور تمدن بشری کے لئے کوئی مفید و ثمر بخش کام سر انجام دے سکتا ہے۔ عقیدہ و ایمان سے خالی انسان کی خودغرضی میں یہ عنصر نمایاں ہوتا ہے کہ ذاتی مفادات کے چکر سے کبھی نہیں نکلتا یا پھر تردد میں پڑا ہوا سر گرداں وجود ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اخلاقی و سماجی مسائل کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانتا۔
چونکہ اخلاقی و اجتماعی مسائل سے مسلسل انسان کا واسطہ رہتا ہے اور ان مسائل میں انسان کسی مکتب عقیدے اور ایمان سے مربوط ہو تو اس کے لئے اپنی ذمہ داری واضح اور روشن رہے گی۔ اگر مکتب و دین اس کی ذمہ داری واضح نہ کریں تو یہ شخص ہمیشہ متردد رہے گا۔ کبھی ادھر کھنچ جائے گا تو کبھی ادھر بہہ نکلے گا یا دوسرے الفاظ میں تھالی کا بینگن بن جائے گا۔
مذہبی ایمانی رجحانات اس چیز کا باعث بنتے ہیں کہ انسان اپنے فردی طبیعی میلانات کے خلاف کام سرانجام دے یہاں تک کہ اپنی تمام تر حیثیت اور ہستی بھی ایمان کی راہ میں لٹا دے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کے نظریات تقدس کا پہلو لئے ہوئے ہوں اور انسانی وجود پر حاکمیت مطلق حاصل کر لیں۔ فقط مذہبی قوت یہ قدرت رکھتی ہے کہ نظریات کو تقدس عطا کر سکے اور پوری طاقت سے انسان پر ان کا حکم لاگو کر سکے۔
بعض اوقات لوگ عقیدے و مذہب کے بغیر دباؤ عداوت اور انتقامی جذبات کے تحت ظلم و ستم اور دھونس کے خلاف شدید ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس راہ میں فداکاری کرتے ہیں۔ اپنی جان مال عزت و آبرو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اس کی مثالیں ہم دنیا کے گوشہ و کنار میں دیکھتے ہیں۔
لیکن ایک مذہبی و غیر مذہبی نظریہ کا فرق یہ ہے کہ جہاں کہیں مذہبی نظریہ کا مسئلہ ہو اور اسے تقدس حاصل ہو جائے تو قربانی مکمل رضامندی اور طبیعی طور پر دی جاتی ہے۔ لہذا رضا و رغبت اور ایمان کے تحت انجام پانے والا کام ایک طرح کا انتخاب ہوتا ہے۔ جبکہ عالمی اور خارجی دباؤ کے تحت ہونے والا کام ایک طرح کا دھماکہ ہوتا ہے۔
اگر انسان کا تصورِ کائنات فقط مادی ہو اور حقیقت کو محسوسات میں منحصر قرار دیتا ہو تو پھر ہر قسم کی عقیدہ پرستی اور اجتماعی و انسانی نظریات ان حسی واقعات کے برخلاف ہوں گے جنہیں انسان کائنات کے ساتھ اپنے رابطے کے دوران محسوس کرتا ہے۔
حسی تصور کائنات کا نتیجہ عقیدہ پرستی نہیں بلکہ خود پرستی ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ پرستی کی بنیاد ایسا تصور کائنات نہ ہو کہ جس کا منطقی خود وہی عقیدہ نہ ہوتو پھر تصور کائنات صرف خیال پرستی تک محدود رہے گا۔ خشک سرد مادی اور میکانیاتی دنیا کو زندہ باشعور اور آگاہ دنیا میں بدل دیتا ہے۔ مذہبی ایمان دنیا اور کائنات کے بارے میں انسان کی فکر و نظر بدل دیتا ہے۔
علم و ایمان؛ نفسیات کی نظر میں
ان سب کے علاوہ ہر انسان کی جبلت میں قابل پرستش و مقدس حقائق و واقعات کی طرف میلان موجود ہے۔ انسان میں متعدد میلانات اور بعض غیر مادی صلاحتیں مخفی ہوتی ہیں۔ جنہیں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ انسانی میلانات مادی میلانات تک محدود نہیں ہیں۔ اسی طرح معنوی اور روحانی میلانات بھی فقط تلقینی و اکتسابی نہیں ہوتے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سائنس بھی قبول کرتی ہے۔
ویلیام جیمز کہتے ہیں: "یہ دنیا ہمارے جتنے بھی میلانات کا محرک ہو ہماری بیشتر آرزوؤں اور خواہشوں کا سرچشمہ عالم ماورائے طبیعت ہے کیوں کہ ان میں سے بیشتر کی مادی توجیہہ نہیں کی جاسکتی۔”[7]
چونکہ یہ میلانات وجود رکھتے ہیں لہذا ان کی نشو و نما ضروری ہے۔ اگر ان کی صحیح نشو و نما نہ ہو اور ان سے ٹھیک طرح فائدہ نہ اٹھایا جائے تو پھر یہ منحرف راستے پر چل نکلتے ہیں اور ناقابل تصور نقصانات کا باعث بنتے ہیں۔ بت پرستی شخصیت پرستی طبیعت پرستی اور ہزاروں دوسری پرستشیں اسی انحراف سے پیدا ہوتی ہیں۔
چونکہ انسان کیلئے کسی عقیدہ و ایمان اور نظریے کا حامل ہونا ضروری ہے اور دوسری طرف فقط مذہبی ایمان ہی ایسا ایمان ہے جو حقیقی طور پر انسان کو اپنے زیر اثر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مزید براں انسان اپنی سرشت کے تحت کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے جسے وہ مقدس قراردے کر اس کی پرستش کرے۔ پس واحد راستہ یہ ہے کہ ہم مذہبی ایمان کی تقویت کریں۔
قرآن کریم ہی سب سے پہلی کتاب ہے جس نے بڑی صراحت سے مذہبی ایمان کو عالم خلقت کے ساتھ ہم آہنگ بتایا ہے: «أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»[8]
"کیا وہ دین خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی جستجو کرتے ہیں جبکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کے حضور سر تسلیم خم ہے۔”
اور علم اور ایمان میں ایک مستحکم رابطہ برقرار کیا۔ نیز یہ کہ قرآن مذہبی ایام کو انسانی فطرت کا حصہ قرار دیتا ہے: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»[9]
"حق طلب ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کر لے وہی دین جو اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔” اور انسانی فطرت میں علم و ایمان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔
خاتمہ
علم اور ایمان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ برقرار ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر غیر ضروری طور پر ترجیح دینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں، علم اور ایمان ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ اس کے باوجود، یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ علم کے بغیر ایمان شدت پسندی کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ ایمان کے بغیر علم اخلاقی پستی کا سبب ہو سکتا ہے۔
حوالہ جات
[1]۔ اقبال، احیای فکر دینی در اسلام، ص۲۰۳۔
[2]۔ ڈیورانٹ، لذات فلسفہ، ص۲۹۲۔
[3]۔ ڈیورانٹ، لذات فلسفہ، ص۱۳۵۔
[4]۔ ڈیورانٹ، لذات فلسفہ، ص۲۰۶۔
[5]۔ رسل، زناشوئی و اخلاق۔
[6]۔ سارٹن، شش بال علم، ص۳۰۵۔
[7]۔ جیمز، دین و دوران۔
[8]۔ سورہ آل عمران، آیت ۸۳۔
[9]۔ سورہ روم، آیت۳۰۔
منابع و مآخذ
۱۔ قرآن مجید۔
۲۔ اقبال، محمد، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، تہران، پایا، ۱۳۵۶ش۔
۳۔ جیمز، ویلیام، دین و دوران، ترجمہ مهدی قائنی، قم، دارالفکر، ۱۳۸۷ش۔
۳۔ دیورانٹ، ویل، لذات فلسفہ، ترجمہ عباس زریاب خوئی، تہران، اندیشہ، ۱۳۴۴ش۔
۴۔ رسل، برٹریند، زناشوئی و اخلاق، ترجمہ ابراهیم یونسی، تہران، اندیشہ، ۱۳۴۷ش۔
۵۔ سارٹن، جورج، شش بال: مردان علم در رونسانس، ترجمه احمد آرام، تہران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1364ش۔
مضمون کا مأخذ (تلخیص اور ترمیم کے ساتھ):
مطہری، مرتضی، انسان اور ایمان، تہران ایران، صدرا، ۱۴۰۲ش۔ (نسخہ اردو توسط شبکہ الامامین الحسنین)۔