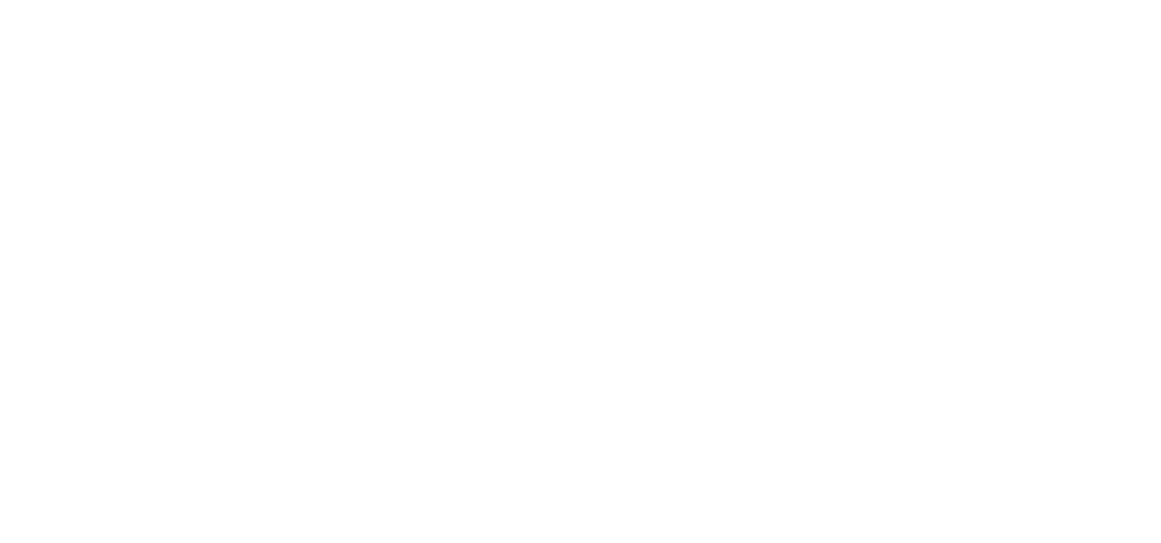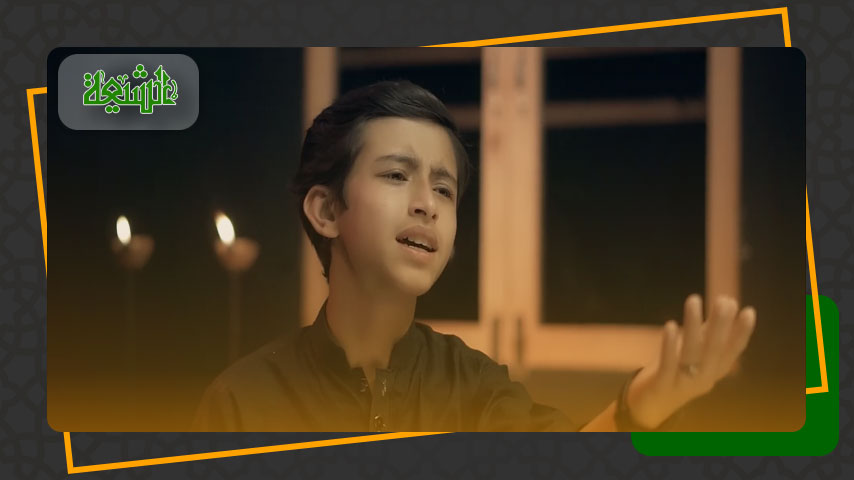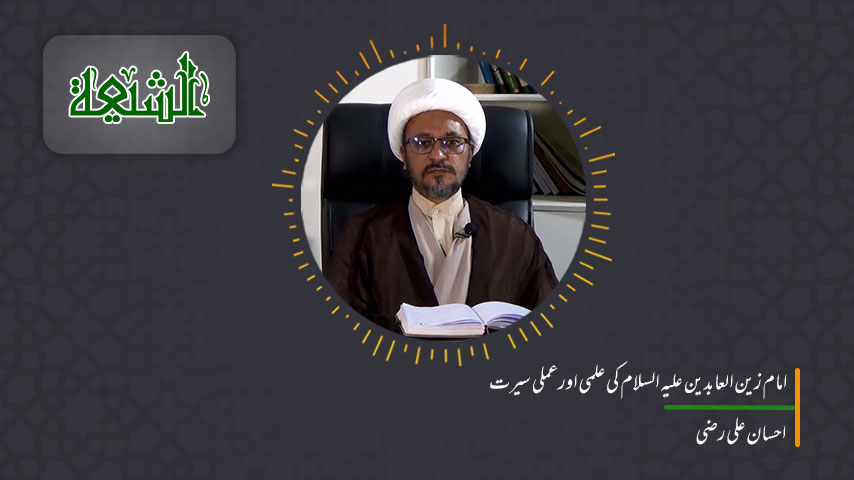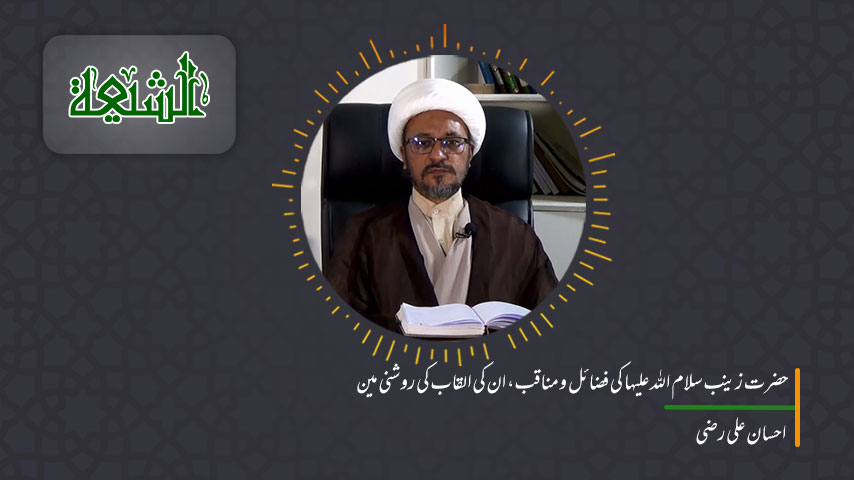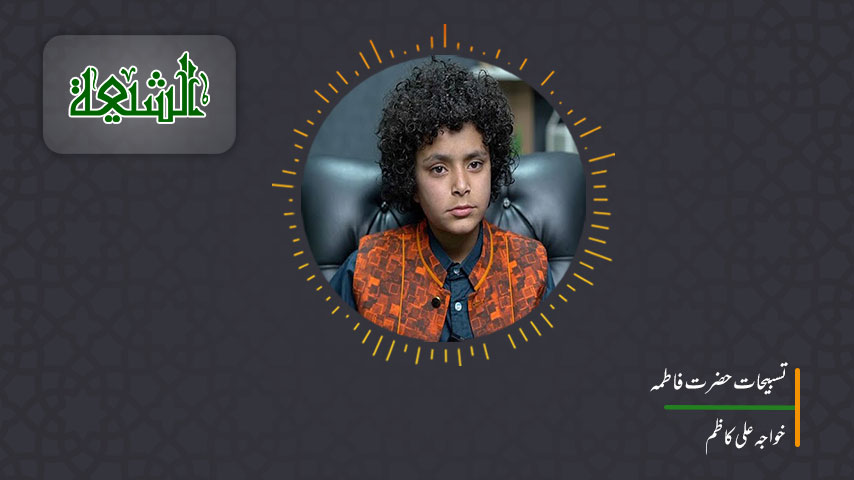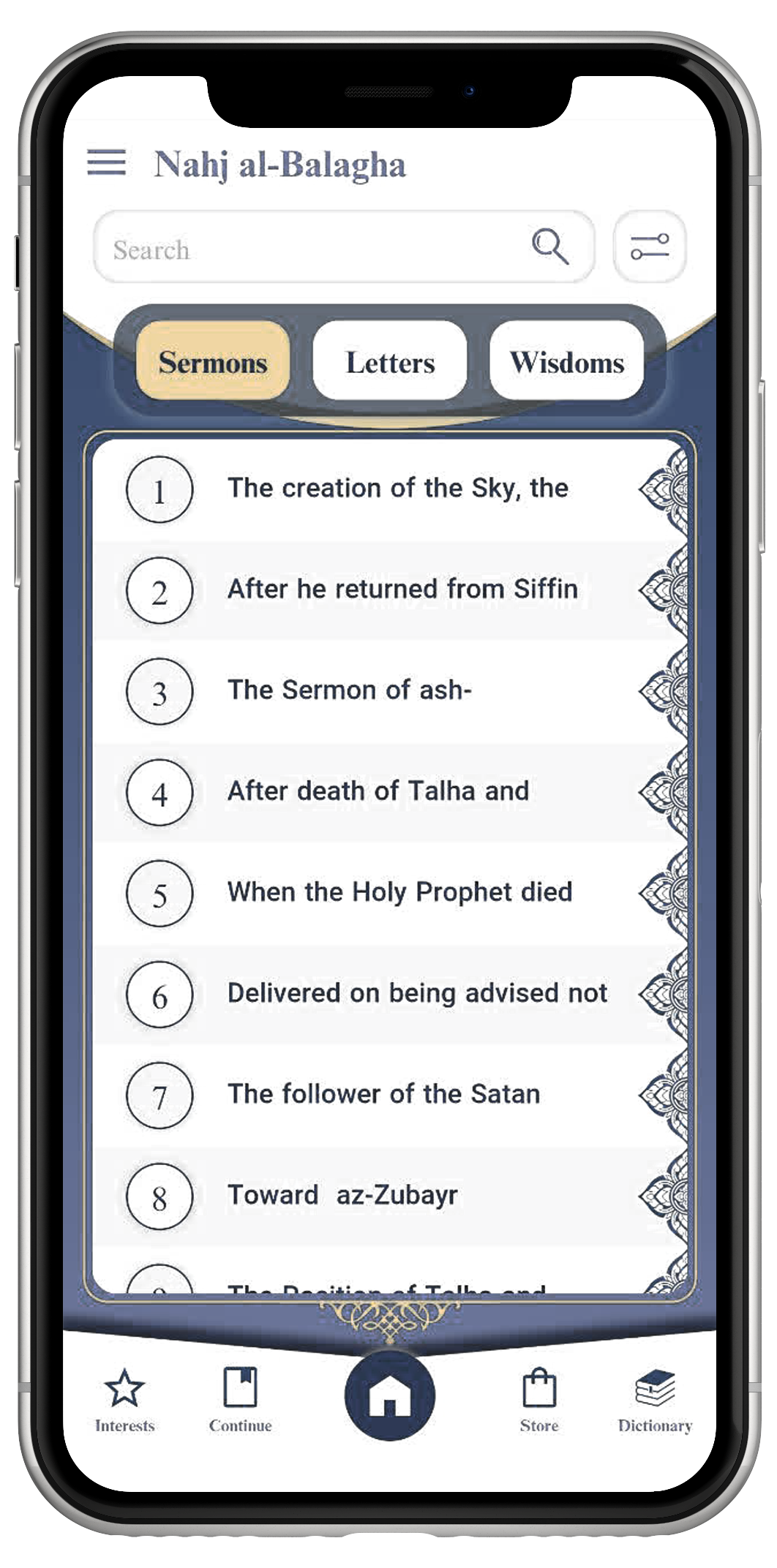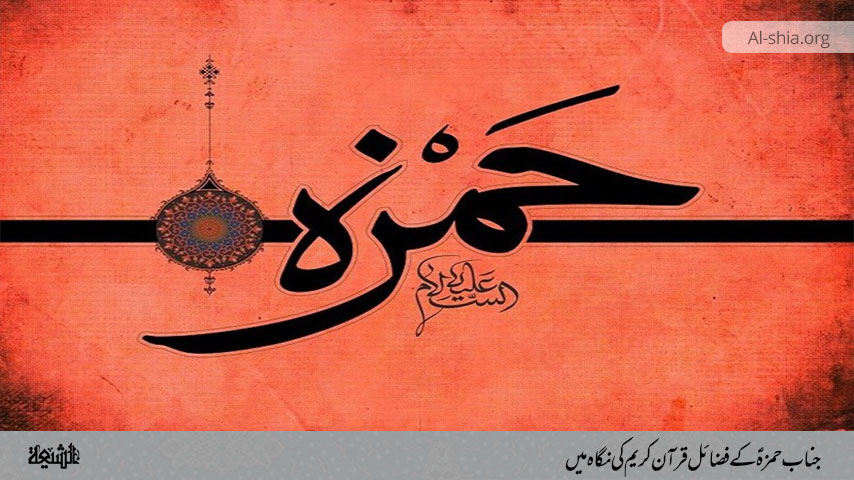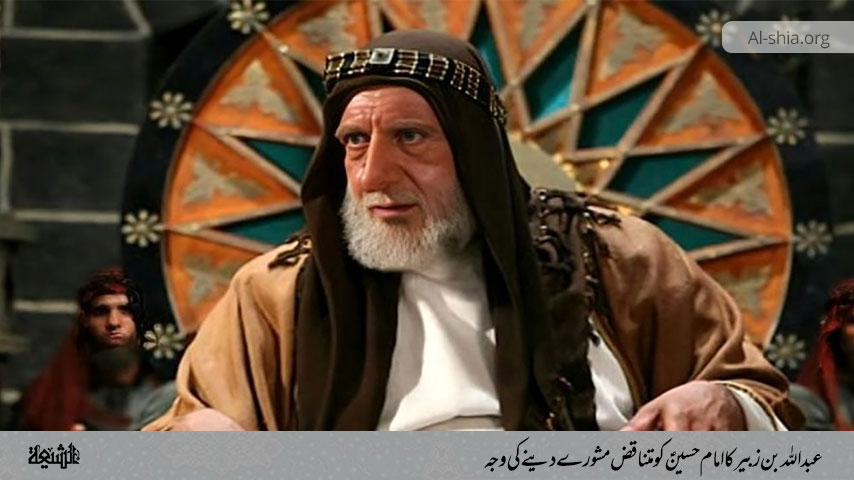وحی کو حاصل کرنے اور پہنچانے کے علاوہ، پیغمبر اکرم (ص) کا ایک بڑا فریضہ وحی کی وضاحت اور قرآن کریم کی تفسیر کرنا بھی ہے۔ یہ اہم ذمے داری خداوند متعال نے پیغمبر (ص) اور ائمہ معصومین (ع) کو عطا کی ہے۔
قرآن کی تفسیر نبی اور ائمہ معصومین سے مخصوص
وحی کے حاصل کرنے اور پہنچانے کے علاوہ پیغمبر اکرم (ص) کا ایک عہدہ، وحی کی توضیح اور الٰہی احکام کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ قرآن کریم احکام کے کلیات اور قوانین کے ایک مجموعہ کی صورت میں پیغمبر اکرم (ص) پر نازل ہوا ہے اور خود ان کے جزئیات اور احکام کی تفصیل و توضیح نہیں بیان کی ہے اور چند موارد کے علاوہ ان کی تفصیل و توضیح پیغمبر اکرم (ص) اور ائمۂ معصومین (ع) کے ذمہ قرار دی ہے۔
مثال کے طور پر قرآن کلی صورت میں نماز کا حکم دیتا ہے اور مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن یہ کہ نماز کیا ہے؟ کتنی رکعت ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس کے شرائط و جزئیات کیا ہیں؟ قرآن میں بیان نہیں ہوئے ہیں۔
اس کلی حکم اور اس جیسے بہت سے احکام کی تفصیل پیغمبر اکرم (ص) کے ذمہ چھوڑ دی ہے۔ اس بنا پر احکام الٰہی کی تفسیر و توضیح پیغمبر اکرم (ص) کا فرض منصبی ہے۔
قرآن کریم بھی وحی کی تفسیر و توضیح کے عہدہ کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اسے پیغمبر اکرم (ص) کے فرائض میں سے شمار کرتا ہے:
”وَ أَنْزَلْنَا اِلَیکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیهِم”[1] ہم نے قرآن کو آپ (ص) پر نازل کیا تاکہ لوگوں کے لئے ان باتوں کو واضح کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں۔
بعید نہیں ہے کہ سورۂ آل عمران کی آیت جیسی آیتوں میں، کہ جن میں تعلیم کو تلاوت کے ساتھ استعمال کیا ہے، تعلیم سے مقصود وحی و قرآن کی تفسیر و توضیح کے متعلق پیغمبر اکرم (ص) کا عہدہ و منصب بیان کرنا ہو۔
حقیقت میں پیغمبر اکرم (ص) جس وقت وحی پہنچاتے تھے، اس وقت دو اہم فریضے آپ (ص) کے ذمے ہوتے تھے، ایک یہ کہ کلام وحی کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے اور دوسرے یہ کہ آیتوں کے مقاصد و مضامین کی ان کے لئے تفسیر و توضیح فرماتے تھے اور ان کو قرآن کے احکام و معارف سے آشنا کرتے تھے۔
قرآن فرماتا ہے:
”لَقَد مَنَّ اللّٰهُ عَلٰی الْمُؤمِنِینَ اِذ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِن أَنفُسِهِم یَتلُوا عَلَیهِم آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتَابَ وَ الْحِکمَةَ وَ اِنْ کَانُوْا مِنْ قَبلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ”[2]
یقینا خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر آیات الٰہیہ کی تلاوت کرتا ہے انھیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگر چہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔
اس آیۂ مبارکہ اور اس کے مشابہ دوسری آیتوں میں پہلا فریضہ یعنی آیات کی تلاوت و قرائت ”یَتْلُوْا” کی تعبیر سے بیان ہوا ہے اور دوسرے فریضہ یعنی احکام و مطالب کی تفسیر و توضیح کے لئے ”تعلیم” کی تعبیر سے استفادہ کیا گیا ہے۔
خلاصہ یہ کہ وحی کی توضیح، احکام الٰہی کی تفصیل اور قرآن کریم کی تفسیر مذکورہ معنی میں ایسا کام ہے کہ جس کی صلاحیت پیغمبر اکرم (ص) اور ائمۂ معصومین (ع) کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا اس لئے کہ صرف یہی ہستیاں ہیں جو خدا داد علم کے ذریعے الٰہی علوم و معارف سے آشنا ہیں۔
اب مذکورہ نکتہ پر توجہ کرنے سے مفسرین کا فریضہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوچکا ہے وحی کی تفسیر و توضیح، احکام کی تفصیل اور آیات قرآن کی تفسیر کا عہدہ اور اس کی صلاحیت در اصل پیغمبر اکرم (ص) کو حاصل ہے اور آنحضرت (ص) نے اپنی مبارک زندگی کے زمانہ میں جہاں تک ممکن تھا لوگوں کو قرآن کے معارف سے آشنا کیا۔
اس زمانہ میں مفسرین کا بھی فریضہ ہے کہ ان روایات و احادیث کی طرف رجوع کریں جو صحیح اسناد کے ساتھ پیغمبر اکرم (ص) سے اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں اور ان کی بنیاد پر مربوط آیتوں پر توجہ اور غور و فکر کریں اور اپنی فکر و نظر کو پیغمبر اکرم (ص) کی توضیح و تفسیر کے حدود ہی کے اندر رکھیں۔ اور جہاں آنحضرت (ص) نے اس ثقل اکبر اور قرآن مستحکم کی تفسیر و توضیح نہ کی ہو وہاں ثقل اصغر یعنی اہل بیت اور ائمۂ معصومین (ع) سے تمسک کریں۔
اس سلسلہ میں بھی دینی علوم و معارف کے ماہر و عالم افراد کا فریضہ ہے کہ ایسی احادیث اور روایات کے ذریعہ قرآن کریم کو سمجھا جائے جن کی سند صحیح ہو اور وہ مشکل کو حل کرنے والی ہوں۔
اس بنا پر سب سے پہلا معیار قرآن اور معارف دین کے صحیح سمجھنے میں وہ توضیح و تفسیر ہے جو پیغمبر اکرم (ص) اور ائمۂ معصومین (ع) سے وارد ہوئی ہے۔ نتیجہ میں ایک مفسر کا اولین اور اصلی فریضہ اس تفسیر کا سمجھنا اور بیان کرنا ہے جو پیغمبر اکرم (ص) اور ائمۂ طاہرین (ع) سے وارد ہوئی ہے اس لئے کہ صرف علوم اہل بیت (ع) ہی کی روشنی میں معارف قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔
قرآن کی تفسیر، قرآن سے
اگرچہ قرآن کی آیتیں ظاہری اعتبار سے الگ الگ صورت میں اور ان میں ہر ایک یا کچھ آیتیں ایک خاص مطلب کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن صحیح فہم و تفسیر اس صورت میں وجود میں آتی ہے کہ ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق آیتوں پر توجہ دی جائے۔ بہت سی آیات قرآن ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے مضامین و مطالب کے صدق پر گواہی دیتی ہیں۔
امیرالمومنین حضرت علی (ع) اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں:
”کِتَابُ اللّٰهِ تُبصِرُونَ بِهِ وَ تَنطِقُونَ بِهِ وَ تَسمَعُونَ بِهِ وَ یَنطِقُ بَعضُهُ بِبَعضٍ وَ یَشْهَدُ بَعضُهُ عَلٰی بَعضٍ وَ لایَختَلِفُ فِی اللّٰهِ وَ لا یُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللّٰهِ۔”[3]
یہ کتاب خدا ہے جو تمھیں حق کا بینا، گویا اورشنوا بناتی ہے، اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصوں کی تفسیر و توضیح کرتا ہے اور ایک دوسرے کی گواہی دیتا ہے یہ قرآن خدا کے بارے میں اختلاف نہیں رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کو خدا سے الگ نہیں کرتا ہے۔
قرآن سے قرآن کی تفسیر کے موارد میں سے نمونہ کے طور پر سورۂ شوریٰ کی گیارہویں آیت ”لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء وَ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ”[4] اور سورۂ فتح کی دسویں آیت ”یَدُ اللّٰهِ فَوقَ أَیدِیهِم”[5] کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
”لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء” قرآن کے محکمات میں سے اور اس کا معنی روشن و واضح ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی چیز خدا کے مانند نہیں ہے، خداوند متعال بے مثل حقیقت ہے۔ آیۂ ”یَدُ اللّٰهِ فَوقَ أَیدِیهِمْ” بتاتی ہے کہ خدا کا ہاتھ تمام لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔
اگرچہ اس آیت نے خداوند تعالی کی طرف ہاتھ کی نسبت دی ہے لیکن آیۂ ”لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء” اس ظاہری معنی کی نفی کرتی ہے اور اس کی طرف توجہ کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ”ید” سے مراد اس کا ظاہری معنی یعنی ”ہاتھ” نہیں ہے، بلکہ کنائی معنی مثلاً قدرت وغیرہ مقصود ہے۔
اس بنا پر آیۂ ”یَدُ اللّٰهِ فَوقَ أَیدِیهِم” کی تفسیر و توضیح آیۂ ”لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء” کی طرف توجہ کئے بغیر تفسیر کی صحیح روش سے خارج ہونا ہے اور ممکن ہے خطا سرزد ہو جائے اور غلط تفسیر کی بنا پر خدا کی جسمانی اور جھوٹی تصویر دکھا دی جائے۔
لہٰذا قرآن کریم کی تفسیر میں اس نکتہ کی طرف توجہ دینا لازم ہے کہ آیات کو ایک دوسرے سے مرتبط ہونے میں مورد توجہ قرار دیں اور ان کا مطلب خود قرآن کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں۔
قرآن فہمی میں عقلائی اصول و قواعد کی رعایت
قرآن کریم کے صحیح سمجھنے میں عقلائی محاورہ کے اصول و قواعد کی رعایت کرنا ہے۔ خصوصاً جس وقت کہ کسی آیت کے متعلق پیغمبر اکرم (ص) یا ائمۂ معصومین (ع) سے کوئی صحیح روایت اور واضح بیان دسترس میں نہ ہو تو آیات قرآن کے صحیح سمجھنے میں عقلائی محاورہ کے اصول و قواعد کی رعایت کی ضرورت دوگنی ہوجاتی ہے۔
اسی موقع پر ان بزرگان دین اور مفسرین اور علوم اہل بیت (ع) سے آشنا علماء کا کردار اور اثر، کہ جنھوں نے اپنی عمر معارف قرآن اور علوم اہل بیت (ع) کے سمجھنے میں گزاری ہے، قرآن کے صحیح سمجھنے اور معارف دین کی توضیح میں ظاہر ہوتا ہے۔
وہی حضرات عقلائی محاورہ کے اصولوں کے مطابق، قرآن کے عام و خاص کی تشخیص دیتے ہیں اور ہر ایک کے معنی کے حدود معین کرتے ہیں، مطلق و مقید کی نشاندہی کرتے ہیں اور آیات کی ایک دوسرے سے تفسیر کرتے ہیں، ایک آیت کے دوسری آیت پر ناظر اور اس سے متعلق ہونے کی تعیین کرتے ہیں اور تفسیر کے وقت اس پر توجہ رکھتے ہیں۔
مفسرین کی فہم کے مراتب اور علمی ذمہ داریاں
دوسرا نکتہ کہ جس کی طرف توجہ دینا لازم ہے قرآن اور معارف دین سمجھنے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام اور مختلف علمی شعبوں میں سب کے لئے قابل قبول ہے اور وہ فہم کے مراتب کا پایا جانا ہے اور صحیح سمجھنے میں اس کا ذہنی قوت اور کوشش و کاوش کے مطابق ہونا ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ:
فقہی مباحث میں ایک مسئلہ ہے کہ جس کا تقریباً تمام فقہاء فتویٰ دیتے ہیں اور مقلِّد کا فریضہ سمجھتے ہیں، وہ اعلم کی تقلید ہے۔ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ فقہ و استنباط احکام کے شعبے میں مہارت اور فقاہت کے بہت سے مرتبے ہیں اور ہر مکلف کا فریضہ ہے کہ فقیہ اعلم یعنی اس مرجع کی تقلید کرے جو احکام کے استنباط میں دوسروں سے زیادہ فہم، مہارت اور فقاہت کا حامل ہو۔
البتہ دوسرے مراجع جو کہ قوت استنباط کے اعتبار سے اس فقیہ اعلم کی حد میں نہیں ہیں وہ بھی فقیہ اور مجتہد ہیں لیکن وہ بعد کے مراتب میں قرار پاتے ہیں۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فقہاء کا یہ فتویٰ کہ اعلم کی تقلید لازم ہے، ایک عقلائی سیرت و روش سے صادر ہوا ہے۔ بالکل جیسے اس ماہر اور اسپشلسٹ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا جو برسوں سے ڈاکٹری اور طبابت کا تجربہ رکھتا ہے اور اسے اس شخص پر ترجیح دینا کہ جس نے آج ہی ڈاکٹری کی سند لی ہے، ایک عقلائی سیرت و روش ہے اور اس روش کے برخلاف عمل کرنا عقلاء کے نزدیک مذموم ہے۔
معارف قرآن کی باریکیاں سمجھنے اور ان کی تشخیص کی صلاحیت علوم اہل بیت (ع) کے عالم اور ماہر افراد کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جنھوں نے اپنی زندگی قرآن اور دینی معارف کے سمجھنے میں صرف کی ہے۔
قرآن فہمی اور اس آسمانی کتاب کی تفسیر کے مراتب کے اعتبار سے واضح بات ہے کہ مذکورہ امور اور نکات پر جس قدر توجہ اور غور کیا جائے گا آیات الٰہی کی تفسیر میں اتنا ہی غلطیوں کا احتمال کم ہوگا اور ہم اس آسمانی کتاب کو زیادہ سے زیادہ صحیح سمجھیں گے۔
قرائن اور آیات کی شان نزول پر توجہ
قرآن کریم تمام زمانوں اور نسلوں کے لئے نازل ہوا ہے اور اس کے مخاطب ہر زمانے کے لوگ ہیں، لیکن قرائن، شان نزول اور وہ موقع و محل کہ جن میں آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں وہ اولین مخاطبین اور نزول قرآن کے زمانہ کے لوگوں کے لئے ایسی واضح و روشن ہوتی تھیں کہ اس کے معنی و تفسیر میں کسی شک و شبہہ اور اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہتی تھی۔
اس کے علاوہ اگر کوئی آیت، مبہم اور غیر واضح نظر آتی تھی تو لوگوں کا پیغمبر اکرم (ص) تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ لیکن آج زمانۂ نزول سے دور ہونے اور بعض قرائن اور شان نزول کے مخفی ہوجانے کے امکان سے قرآن کے صحیح سمجھنے میں کوشش و کاوش کی ضرورت کئی گنا زیادہ اہمیت کی حامل ہوگئی ہے۔
دوسری طرف قرآن کریم میں استعمال شدہ الفاظ کے حقیقی و لغوی معنیٰ کی اطلاع، ان مسائل میں سے ہے کہ جن کے بغیر قرآن کا صحیح سمجھنا اور اس کی درست تفسیر کرنا ممکن نہیں ہے۔
ممکن ہے کسی معنی کی تبدیلی سے غفلت جو کبھی کسی زبان میں مرور زمانہ سے واقع ہوتی ہے، غلطی اور بد فہمی کا باعث بن جائے۔
مثال کے طور پر لفظ ”تقیہ” کا معنی و مفہوم سب کے لئے واضح ہے۔ عام طور پر اس لفظ سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنا عقیدہ و مذہب مخفی رکھے اور ایسا ظاہر کرے کہ اس کا مخاطب اس کے حقیقی عقیدہ و مذہب سے آگاہ نہ ہو، اگرچہ تقیہ کے لغوی معنی پرہیزگاری کے ہیں اور قرآن و نہج البلاغہ میں ان ہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ولو لفظ تقیہ قرآن میں نہیں ہے لیکن لفظ ”تقاة” جو کہ تقیہ اور تقویٰ کے مترادف ہے، آیۂ ”اِتَّقُواْ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ”[6] میں آیا ہے۔
قرآن کریم اور کلامی محاسن
اگر چہ قرآن کریم، جیسا کہ خود کہتا ہے، واضح اور آشکار زبان میں نازل ہوا ہے اور ہر شخص اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق اس آسمانی کتاب سے مستفید ہوسکتا ہے۔ لیکن اس نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے کہ قرآن سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور کلام و بیان کے تمام محاسن (خوبیوں) سے آراستہ ہے اور واضح ہے کہ مذکورہ نکات کی طرف توجہ دینا بھی قرآن کریم سے صحیح استفادہ کے بنیادی شرائط میں سے ہے۔
قرآن کریم میں کہیں کہیں ایسا ہے کہ ایک آیت کسی حکم کو عام اور کلی صورت میں بیان کرتی ہے اور دوسری آیت اس حکم کے حدود کو واضح کرتی ہے۔ یا ایک آیت میں کسی حکم کو مطلق طور پر بیان کیا ہے اور دوسری آیت سے اس کی قید و شرط معلوم ہوتی ہے، مثال، کنایہ، استعارہ، مجاز و غیرہ کے استعمال کے ذریعہ، مطالب کا بیان ان اسلوبوں میں سے ہے کہ جن کا استعمال قرآن کریم میں ہوا ہے، اور چونکہ قرآن کے مخاطب انسان ہیں اور مذکورہ طرز و اسلوب، مقصود و مطلب بیان کرنے میں انسانی اور عقلائی کلام کے محاسن میں سے سمجھے جاتے ہیں، لہٰذا قرآن بھی مذکورہ اسالیب کو اپنے احکام و معارف کے بیان میں بہترین طرز کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔
اس بنا پر قرآن میں استعمال شدہ اسالیب وہی اسالیب ہیں جو عقلاء اپنے مقاصد و مطالب بیان کرنے میں استعمال کرتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ کلامی و بیانی فنون کے استعمال کی جو نوع اور کیفیت قرآن میں پائی جاتی ہے وہ مرتبہ، حسن اور طرز و اسلوب کے اعتبار سے، انسانی کلام میں پائے جانے والے محاسن کے استعمال سے مقائسہ اور موازنہ کے قابل نہیں ہے۔
اس بات کی دلیل بھی یہ ہے کہ قرآن کریم خداوند متعال کا کلام ہے جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ بیان کے ساتھ پیغمبر اکرم (ص) پر نازل ہوا ہے کہ جس نے فن فصاحت و بلاغت کے اصول انسان کو سکھائے ہیں۔ اس الٰہی کتاب نے سب سے زیادہ خوبصورت اور فصیح و بلیغ بیان کے ساتھ لوگوں کو توحید، ہدایت، تکامل اور سعادت و کامیابی کی طرف دعوت دی ہے۔
خاتمہ
تفسیر قرآن ایک نہایت اہم عمل ہے، جس میں پیغمبر اکرم (ص) اور ائمہ معصومین (ع) نے قرآن کی آیات کی وضاحت اور الٰہی احکام کی تفصیل فراہم کی۔ قرآن کریم میں احکام کے کلیات تو موجود ہیں، لیکن ان کی جزئیات کی وضاحت اور صحیح تفسیر ان کا فریضہ ہے۔ اس مضمون میں قرآن کی صحیح تفسیر کے لیے کچھ اہم نکات بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے.
حوالہ جات
[1] سورۃ نحل، آیۃ ۴۴
[2] سورۃ آل عمران، آیۃ ۱۶۴
[3] سید رضی، نہج البلاغۃ، خطبۃ ۱۳۳
[4] سورۃ شوری، آیۃ ۱۱
[5] سورۃ فتح، آیۃ ۱۰
[6] سورۃ آل عمران، آیۃ ۱۰۲
فہرست منابع
۱: القرآن الکریم.
۲: سید رضی، نَهجُ البَلاغة، قم، دار الهجرة، ۱۴۰۹ھ ق۔
مضمون کا مآخذ (تلخیص اور ترمیم کے ساتھ)
مصباح یزدی، محمد تقی، قرآن نہج البلاغہ کے آئینہ میں؛ مترجم: فیضی ہندی، ہادی حسن، قم، مجمع جہانی اہل بیت (ع)، ص101 الی110۔